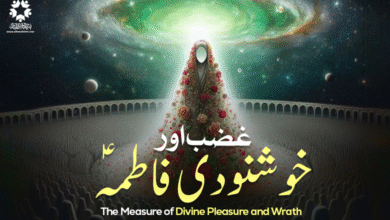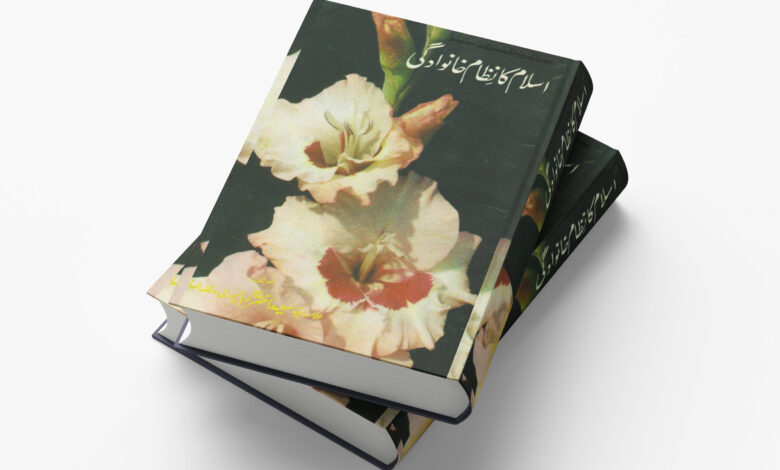
اسلام کا خانوادگی نظام (بخش اول)
تحریر: مرحوم رئیس المبلغین علامہ سید سعید اختر رضوی گوپالپوری صاحب
نوٹ: مندرجہ ذیل تحریر مرحوم رئیس المبلغین علامہ سید سعید اختر رضوی گوپالپوری (نوراللہ مرقدہ ) کی کتاب ” اسلام کا خانوادگی نظام”سے اقتباس ہے جو آپ کے آثار سے متعلق ویب سائٹ(www.allamahrizvi.com ) پر موجود ہے۔ البتہ بعض موارد پر مزید حوالوں اور مناسب مطالب کا اضافہ کیا گیا ہے (ادارہ)۔
فہرست مندرجات
پہلا باب: نظام خانوادگی اور اسلامی نقطہ نظر
۴۔مشترکہ خاندان اور جداگانہ خاندان
۴۔ مشترکہ خاندان کے فوائد اور خرابیاں
۵۔جداگانہ خاندان کے فوائد اور خرابیاں
6۔ اسلامی معاشرت کا حکیمانہ اصول
خانہ داری کے علیحدہ انتظامات اور صلۂ رحم
دوسرا باب: والدین اور اولاد کے حقوق اور ذمہ داریاں
2۔ حقوق والدین کے بارے میں شدت تاکید کا سبب
ب۔بچوں اور نوجونواں کی زندگی کے تین دور
پہلا دور: پیدائش سے سات برس تک
دوسرا دور: آٹھ برس سے چودہ برس تک
تیسرا دور: چودہ پندرہ برس کے بعد
ج۔ تینوں مراحل کے متعلق ہدایات
۵۔ والدین کی ذات باری سے مشابہت مالی حقوق کے لحاظ سے
۸: ماں کے حقوق کی عظمت و برتری
پہلا باب: نظام خانوادگی اور اسلامی نقطہ نظر
۱۔ نظام خانوادگی کی اہمیت
ایک سنجیدہ اور متوازن خاندانی نظام خوش گوار زندگی کی بنیاد بلکہ ترقی پذیر معاشرے کی اساس ہے۔ مذہب انسان کو بارگاہ الہی سے قریب تر کرنے کے لئے آتا ہے۔اور یہ مقصد ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ایک ایسا ماحول پیدا نہ ہو جائے جو دینی مطالبات سے ہم آہنگ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی دین اس وقت تک مکمل نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کےتعلیمات واضح طریقے سے یہ نہ بتائیں کہ خاندان میں ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا درجہ ہے؟۔خاندان انسانی معاشرہ کی ایک ایسی اکائی ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے انتہائی قریبی رابطہ رکھتےہیں اور اس قربت ہی سے کشاکش اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک اپنے فرائض و حقوق کی غیرمبہم (روشن)تصویر ہر ایک کے پیش نظر نہ ہو کشمکش کا پیدا ہونا یقینی ہے۔
اگر کوئی دین نظام خانوادگی کی پیچیدگیوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو جلد یا دیر سے اس کے ماننے والے اس دین سے بغاوت کر بیٹھتے ہیں اور سرکشی کا سیلاب مذہبی اقدارکو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ اس کا سبب ظاہر ہے جو ماحول ان کو نصیب ہوتا ہے، جس سماجی نظام میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ اس دین کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا اورگردو پیش کے غیرشعوری اثرات سے متاثر ہوتے ہوتے وہ مذہب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار ایک وقت ایسا آتا ہے جب دین و مذہب چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے، جس کا عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں رہتا۔
عیسائیت کا حشر ہمارے پیش نظرہے۔ حضرت عیسیٰؑ کے صدیوں بعد اس دین کے پیشواؤں نے فطرت کے تقاضوں کونظر انداز کرتے ہوئےتجرد کی زندگی کو ایک اعلیٰ نصب العین کی حیثیت سے پیش کیا۔ بہت سےمخلص اور پرجوش عیسائیوں نے اس آئیڈیل کو اپنا لیا ۔ راہبوں اور راہباؤں نے اپنے کو دیر اور صومعہ میں بند کرلیا۔ ایک عرصہ تک یہ سسٹم کامیابی سے چلتا رہا۔ اوراس کے بعد فطرت نے اپنا انتقام شروع کردیا۔ راہبوں اور ان کے سرداروں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ وہ عیسیٰ مسیح ؑکے نمایندے ہیں اور راہبائیں عیسیٰ مسیح ؑ کی دلہنیں ہیں۔ اس عقیدہ کے راسخ ہوتے ہی صومعہ اور خانقاہیں جنسی آزادی کا مرکز بن گئیں۔
فطرت ایک فولادی اسپرنگ ہے اس کو جتنا دباؤ گے وہ اتنی ہی طاقت سے اوپر اچھلے گی۔ یہ فطرت کا عیسائیوں سے انتقام ہے جس نے آج عیسائی معاشرے کو اتنا بے لگام اور آزاد بنا دیا ہے کہ دنیا نے کبھی اس کی نظیر نہیں دیکھی تھی۔
اگر دین، فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے اور ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں جب مذہبی لیڈران یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ’’اپنے ہمسایہ سے محبت کرو‘‘ بغیر یہ بتائے ہوئے کہ کیونکر، بغیر اس کے کہ اس کے عملی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔
۲۔ اسلام اور نظام خانوادگی
اسلام آخری دین ہے اور اس کی شریعت بہترین مثالی شریعت ہے۔ ایک غیرجانبدارانہ تبصرہ کرنے والا اس توازن کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا جو اسلامی تعلیمات نے بنیادی تقاضوں اور روحانی ضروریات کے درمیان پیدا کیا ہے۔ اسلام نے اس حیات دنیوی کے لئےبھی ہدایات دی ہیں اور اخروی اور ابدی زندگی کے لئےبھی لائحہ عمل مرتب کرکے دیا ہے۔
یہی وہ شمع ہدایت ہیں جو شاہراہ حیات کے ہر موڑ پر انسان کی چشم بصیرت کو ضیاءبخشتی ہے ۔ یہی وہ مکمل شریعت ہے جس نے نوع انسانی کی کسی احتیاج کو تشنہ توجہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو زندگی۔ جی چاہے اسے تدبیرمنزل کہو یا نظام خانوادگی۔ کےبھی ہر عقدہ کو اس الہی شریعت نے اس خوبصورتی سے حل کر دیا ہے کہ اس سے بہتر تصویرتجویز کرنی احاطہ امکان سے باہر ہے:لیس فی الامکان احسن مما کان۔
مجھے عیسائی مصنفین کے رویہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اسلامی شریعت سے اپنے دین کا موازنہ کرتے ہیں تو ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوجاتے ہیں کیونکہ عیسائیت قوانین و احکام کے لحاظ سے بالکل مفلس ہے جب کہ اسلام ہر نقص سے مبرا اور تمام کمالات کا جامع ہے۔ اس لئے یہ مصنفین اسلام کے حاوی قوانین ہونے کو ایک ’’عیب‘‘ بنا کر پیش کرتے ہیں ۔یا بہ صورت دیگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت اسلام کےتعلیمات عیسائیت کے اخلاقی میعار کے مقابلے میں بہت پست ہیں۔(اس دعوے پر آئندہ تبصرہ کیا جائےگا)۔
۳۔نظام خانوادگی کے ارکان
کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر خاندان یا خانوادہ مکمل نہیں ہوتا۔انسان کی پیدائش کے لئےباپ اور ماں کا وجود لازمی ہے۔ طفلی میں والدین اس کی پرورش و تربیت کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جوان ہوتا ہے اس کے بعد ازدواج کی سنہری زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔پھر نخل تمنا میں اولاد کی صورت میں ثمر آرزو لگتے ہیں۔گویا وہ افراد جنہیں ایوان تدبیرمنزل کا ستون کہنا چاہئے وہ ہیں: باپ، ماں، اولاد،شوہر اور زوجہ ۔ اس کےعلاوہ بہت سے لوگ چند معاونین کے بغیر نہیں رہ سکتے اس لئے اسلام نے اس فہرست میں ’’خادم‘‘ کا بھی اضافہ کیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے آئندہ صفحات میں متذکرہ بالا افراد کے باہمی تعلقات اور ان کے حقوق و فرائض پر اسلام کے ہادیان برحق کے ارشادات کی روشنی میں تبصرہ کرنا مقصود ہے تاکہ برادران ایمانی ان کی مدد سے اپنی گھریلو زندگی کو بہشت زار بنا سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں دنیا و آخرت کی بہبودی کا راز مضمر ہے۔
’’رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ‘‘(سورہ بقرہ، آیت201)۔
۴۔مشترکہ خاندان اور جداگانہ خاندان
متمدن دنیا میں دو قسم کے نظام خانوادگی عام طور پر رائج ہیں: مشترکہ خاندان کا نظام اور جداگانہ خاندان کا نظام۔
الف: مشترکہ خاندان کا نظام
یہ اصول یہ سکھاتا ہے کہ ایک خاندان کے تمام افراد باپ، بیٹا، بھائی، بہن، چچا ، بھتیجے وغیرہ ایک ساتھ رہیں۔ کمانے والوں کی کمائی ان کی انفرادی ملکیت نہیں سمجھی جاتی بلکہ پورے خاندان کی ملکیت ہوتی ہے اور گھر کا بزرگ تمام خاندان کے اخراجات اسی ’’خاندانی آمدنی‘‘سے پورا کرتا ہے۔
ب: جداگانہ خاندان کا نظام
یہ اصول یہ بتاتا ہے کہ ہرشخص اپنے عیال کا بوجھ خود اپنے سر پر اٹھائے۔ اسی بنا پراس کی آمدنی اس کی انفرادی ملکیت ہوتی ہے ’’خاندانی آمدنی‘‘ نہیں سمجھی جاتی۔
ہندؤں میں قدیم الایام سے پہلا اصول رائج تھا اور عربوں میں دوسرا۔ شاید اسی کا اثر رہا ہوکہ ہندوستان میں چچا، پھوپھی، خالہ اور ماموں کی لڑکی کو بھی ’’بہن‘‘ کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف عرب میں وہ محض بنت عم، بنت عمہ، بنت خالہ اور بنت خال(چچا، چچی، پھوپھی اور خالو کی بیٹی) ہے اور بس۔
ہندوؤں کے نزدیک ان رشتہ داروں کو ’’محرمات‘‘ (محرم خواتین) کی فہرست میں داخل کرنے کی بھی شاید یہی وجہ رہی ہو۔ مثلاً ان میں لڑکا اپنے چچا کی بیٹی سے شادی نہیں کرسکتا کیونکہ وہ ’’بہن‘‘ ہے۔ جب کہ عربوں کا رویہ ایسا نہ تھا اور اسلام نے ان کی تائیدبھی کی۔
بہر حال، یہ دونوں اصول بہت پرانے ہیں اور ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی۔
۴۔ مشترکہ خاندان کے فوائد اور خرابیاں
مشترکہ خاندان کا اصول انسانی ہمدردی، اخلاقی عروج اور باہمی اعتماد و تعاون کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ خاندان کے افراد ایک ہی اصل کی فرع ہیں۔فطرت کا اشارہ یہ ہے کہ انہیں خانہ داری کے انتظامات اور گھریلو زندگی میں بھی وحدت کا مظہر ہونا چاہئے۔ یہ یکجہتی قلبی اطمینان اور روحانی سکون کی ضامن ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ اس نظام کی وجہ سے خاندان کے ان افراد کی زندگی مصائب و آلام کا شکار نہیں بننے پاتی جو کسی وجہ سے کسب معاش سے معذور ہوں۔ اس طرح انہیں بے آبروئی اور فکر و تردد کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔گویا یہ نظام خانوادگی ایک بیمہ کمپنی کی طرح بڑھاپے، بیکاری یا بیماری کی صورت میں انسان کی تمام مالی ذمہ داریوں کو اپنے کندھےپر لے لیتا ہے اور گھر والوں کا دماغ فکر فردا کی کشمکش سے محفوظ رہتا ہے۔
یہ تو اس نظام کےمثبت اثرات تھے۔ لیکن یہی فوائد اس کے نقصانات اور منفی اثرات کو جنم دیتے ہیں۔ وہی اطمینان قلب جو اس نظام میں پیدا ہوتا ہے اکثر اوقات گھریلو زندگی کے لیے زہر بن جاتا ہے۔خود غرض اور بے اصول افراد دوسروں کی محنت کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔خاندان کا ایک کاہل فردخود بھی محنت کرنے کے بجائے دوسرے افراد کی کمائی سے آرام اٹھاتا رہتا ہے۔ اسے کسب معاش کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے جب ایک مرتبہ بے کاری کا چسکا لگ جائے تو پھر کام نہ کرنے کے لئے بہت سے بہانے پیدا کر لئے جاتے ہیں۔ آخر اسے کیا پڑی ہے کہ محنت و مشقت کی چکی میں پستا رہے جبکہ دوسرے لوگ اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لئے موجود اور آمادہ ہیں؟ دراصل جب تک اسے اس کا احساس نہ ہو گا کہ وہ اس طرح دوسروں کا استحصال نہیں کر سکتا۔اس وقت تک وہ اپنی روزی خود کمانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کر سکتا۔ نہ تو اس کے دل میں کسب معاش کا حقیقی جذبہ بیدار ہو گا اور نہ ہی اس کی خوابیدہ رگ غیرت میں خون صالح دوڑے گا۔
اسی طرح یہ نظام جدوجہد کے حوصلے کو پامال کرتا ہے۔ اگر ایک شخص روزی حاصل کرنے کے لئےاپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی آمدنی کا معیار اونچا ہوجاتا ہے تو اس کا معیار زندگی فطری طور سے دوسرے ایسے شخص کے مقابلے میں بلند ہوگا جس کی آمدنی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ جدوجہد کی زیادتی معیار زندگی کی بلندی کی متقاضی ہے۔ اگر ایک بھائی کی آمدنی دوسرے بھائی کی آمدنی سے دوگنی ہے تو عقلاً دونوں کے معیار زندگی میں تفاوت ہونا چاہئے۔ لیکن مشرکہ خاندان میں ایسا نہیں ہوپاتا جس کی وجہ سے سعی و کوشش کا جذبہ اور زیادہ کمانے کا ولولہ ختم ہو جاتا ہے۔
اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے خاندان میں ہم آہنگی، محبت اور اعتماد کی فضا پیدا ہو (جیسا کہ اس کے فوائد کو پڑھ کر توقع کی جاتی ہے) یہ گھریلو جھگڑوں اور اختلافات کا بنیادی سبب بن جاتا ہے۔ اگر ایک بھائی مشترکہ خاندان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے جان توڑ محنت کرتا رہتا ہے جبکہ اس کا بھائی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، یا جب وہ آمدنی بڑھانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے تو اس کا بھائی اپنی ترقی کے مواقع کو ہاتھ سے گنواتا رہتا ہے ۔ اس وقت خاندان میں جوزشت ترین صورت میں نمودار ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے۔خاندان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے غصہ اور نفرت کے جذبات بیدار ہوجاتے ہیں۔ معمولی معمولی باتوں کا بد ترین ردعمل سامنے آتا ہے۔ بدگمانی کےشعلےبھڑکنے لگتےہیں۔باہمی اعتماد، محبت اور شادمانی کی جگہ تلخیاں اور نفرتیں ابھر آتی ہیں۔دھیرے دھیرے گھرکی سکون آفرین فضا دنیوی جہنم بن جاتی ہے۔اور یہ پھوڑا بڑھ کر ایسا ناسور بن جاتا ہے کہ افتراق اور جدائی کا نشتر لگائے بغیر اس کا اندمال(علاج) ناممکن ہو جاتا ہے۔
۵۔جداگانہ خاندان کے فوائد اور خرابیاں
جداگانہ خاندان میں ایک طرف وہ خرابیاں نہیں ہیں جو مشترکہ خاندان کے نظام میں پائی جاتی ہیں تو دوسری طرف یہ اس کی خوبیوں سے محروم بھی ہے۔ اپنے دوسرے رشتہ داروں سے بالکل بے تعلق ہو کر رہ جانا یقیناً انسانیت کا گلا گھونٹ دینا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان خودغرضی اور تنگ دلی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ گہری نظر رکھنے والے تو تمام بنی آدم کو پیکر انسانیت کے اعزاز سمجھتے ہیں :
ع: بنی آدم اعضاء یک دیگر اند
مگر یہ نظام خانوادگی ایک ہی ماں کا دودھ پینے والوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ بنا دیتاہے۔
6۔ اسلامی معاشرت کا حکیمانہ اصول
آئیے اب اسلام کے حکیمانہ اصول پر نظر ڈالیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ان دونوں طریقوں کے درمیان ایک ایسی سیدھی شاہراہ بنائی ہے کہ اس پر گامزن ہونے کے بعد انسان دونوں نظاموں کی عطر آگیں خوشبو سے لطف اندوز ہوسکتا ہے اور اس کے باوجود ان کے کانٹوں سے اس کا دامن محفوظ رہتا ہے۔اس نے ذوق بیکاری کے خون فاسد کو رگ تخیل سےباہر نکال دیا یہ کہہ کر کہ ہرشخص اپنے بیوی بچوں کے مصارف کا خود ذمہ دار ہے ۔اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے عیال کا بار دوسروں کے کندھوں پر ڈال دے۔اس طرح مشترکہ خاندان کے مضر اثرات کا قلع قمع کر دیا گیا۔لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہرشخص کو صلۂ رحم کی انتہائی تاکید کی گئی۔رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو واجب کر دیا گیا تاکہ خودغرضی یا اقارب سے بے تعلقی کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اس طرح جداگانہ خاندان کی خرابیوں سے معاشرے کو بچا لیا گیا۔
7۔ واجب النفقہ افراد
اصولاً ان افراد کی تعداد محدود کر دی گئ جن کے اخراجات برداشت کرنا بہرحال لازم ہے۔
حضرت امام صادق ؑ فرماتے ہیں:
’’أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي فِيهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضُ عَلَيْهِمْ وَ وُجُوهُ النَّوَافِلِ كُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً ․․․ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَى وَلَدِهِ وَ وَالِدَيْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ۔
’’اپنا مال صرف کرنے کی جائز صورتیں 24 ہیں ․․․ پس وہ پانچ صورتیں جن میں مال صرف کرنا واجب ہے پس (وہ یہ ہیں): اپنی اولاد پر اور باپ ، ماں پر اور اپنی زوجہ پر اور اپنے غلام(خادم) پر کہ ان کا نفقہ عسرت (تنگی)اور توانگری ہر حال میں لازم ہے‘‘(تحف العقول، ص336-337۔ وسائل الشیعة، ج۲۱ ، ص۵۱۵۔ بحار الانوار، ج۱۰۰، ص۴۴)۔
لیکن اگر انسان فارغ البال اور خوشحال ہو تو پھر تمام رشتہ داروں سے حسن سلوک لازم کر دیا گیا۔ مذکورہ بالاحدیث آگے چل کر ہمیں بتاتی ہے کہ:
’’وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَنْ فَوْقَهُ وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَ التَّنَفُّلُ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقُ‘‘
’’اور پانچ مستحب اخراجات یہ ہیں: وقف شدہ صلہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلۂ رحم کرنا، مومنین سے حسن سلوک کرنا، مستحب صدقات ادا کرنا اور غلاموں کا آزاد کرنا ‘‘(مذکورہ منابع) ۔
صلۂ رحم کے بارے میں بے شمار روایتیں انتہائی تاکید کے ساتھ وارد ہوئی ہیں جو حسب موقع (باب ۴)ذکرکی جائیں گی۔
یہاں پر ایک امر قابل ذکر ہے کہ باوجود یہ کہ ہندوؤں کا خاندانی دائرہ بہت وسیع تھا لیکن ان کے دل میں اپنے اعزہ کے لئے وہ شدید محبت نظر نہیں آتی جو جداگانہ معاشرت کے باوجود عربوں میں پائی جاتی تھی اور جس کی مناسب حد تک تائید اسلام نے بھی کی ہے۔
ایک انسان کے دل میں تحسین اورتعجب کے ملے جلے جذبات ابھر آتے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح اسلام نے مشترکہ خاندان کی مواسات اور جداگانہ خاندان کی اصول باقاعدگی کو ایک دوسرے میں سمو دیا ہے کہ بے اختیار دل پکار اٹھتا ہے کہ ع:
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری
یعنی: بہت سی اچھی اور خوبصورت چیزوں کو دیکھا ہے لیکن تم ایک الگ ہی چیز ہو۔
ہرشخص یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ ایسا حسین اور مکمل نظام اسلام کے قبل کسی نے پیش نہیں کیا تھا۔
آخر کیا فائدہ ایسے مشترکہ نظام رہائش کا جس میں ایک ہندو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک برتن میں کھانے میں مذہب کو حائل پاتا ہے؟ اور کیا نقصان ہے جداگانہ خاندان کا جس میں ایک دوسرے کے گھر کھانا کھا لینے اور اس طرح رشتۂ محبت کو استوار تر بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے؟
8۔ حجاب کا لازمی نتیجہ
اسلامی معاشرے کی بنیاد میں یہ اصول شامل ہے کہ عورتیں نامحرم سے پردہ کریں۔ یہ اصول بھی جداگانہ خاندان کے نظام کی پرزور تائید کرتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے برادران وطن کے تمدن سے متاثر ہو کرمشترکہ خاندان کا اصول اختیار کر لیا ہے۔(جس کی بنا پر )ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب جیسا اہم اسلامی اصول ایک غیراسلامی معاشرے پر قربان کر دیا گیا ہے۔ جس کے نتیجے میں اسلامی تمدن کے کئی دوسرے اہم پہلو تہہ و بالا ہو کر رہ گئے ہیں، مندرجہ ذیل آیتِ قرآنی ہماری خاص توجہ کی طالب ہے:
’’وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ وَ لاٰ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‘‘
’’اور ایماندار عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے جو (عادۃً)سے ظاہر ہو جاتی ہے اور اپنے دوپٹوں (کےا ٓنچل) کو اپنے گریبان پر ڈالے رہیں اور اپنے شوہروں، یا اپنے باپ داداؤں، یا اپنے شوہر کےباپ داداؤں، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھتیجوں، یا اپنے بھانجوں،یا اپنے قسم کی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا گھر کے وہ نوکر چاکر جو مرد صورت ہیں مگر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے۔یا وہ کمسن لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ ہونے دیا کریں‘‘(سورہ نور، آیت 31) ۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فہرست میں نہ تو شوہر کے بھائیوں کا ذکر ہے، نہ شوہر کے بھتیجوں یا بھانجوں کا تذکرہ ہے۔ ایک مسلمان عورت کو ان رشتہ داروں سے بھی اسی طرح اپنی زینت چھپانی اورحجاب کرنا ہے جس طرح دوسرے نامحرموں سے۔ لیکن مشترکہ خاندان کا اصول اس اہم قانون کی پیروی میں آڑے آتا ہے۔اگر ایک مسلمان خاتون اپنے شوہر کے بھائی،بھتیجےیا بھانجے کے سامنے اپنی زینت کو ظاہرکردے تو وہ احکام اسلامی کی محفوظ چہار دیواری سے باہر نکل آئی اور ایک بار اس حد کو پار کرنے کے بعد نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ’’نمائش زینت‘‘ کہاں جا کر رکے گی اور کہیں رکے گی بھی یا نہیں۔
قرآن مجید نے اس سورہ میں ایک دوسرے مقام پر اسے بالکل واضح کر دیا ہے کہ انسان اپنے عیال کابار اپنے باپ ماں کے سر پربھی ہمیشہ نہ ڈالے رہے۔بلکہ اپنی کفالت خود کرے۔ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے چنانچہ حسب ذیل آیت میں ملاحظہ ہو:
’’لَيْسَ عَلَى ․․․ حَرَجٌ ․․․ وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالاٰتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ․․․‘‘
’’اور نہ خود تم لوگوں کے لئے کوئی مضائقہ ہے کہ (بغیر اجازت لئے ہوئے) اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا نانا وغیرہ کے گھروں سے، یا اپنی ماں دادی نانی وغیرہ کے گھروں سے،یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے ․․․‘‘ (سورہ نور، آیت 61)۔
اس آیت میں صریحی طور سے باپ، ماں، بھائی ، بہن وغیرہم کے لئے علیحدہ علیحدہ بیوت( گھروں) کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اس سے کم از کم یہ تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ’’تمہارے گھروں‘‘ اور تمہارے باپ یا تمہاری ماں کے گھروں میں فرق ہے۔( اس کے ساتھ ساتھ وہ یکجہتی اوریگانگت بھی قابل تصور ہے جو اس آیت پرعمل کرنے سے پیدا ہوگی۔ ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا محبت اور اتحاد پیدا کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ ہے)۔
9- ایک سوال
ہم جانتے ہیں کہ عربوں میں جداگانہ خاندان کا طریقہ رائج تھا۔قیاس یہ کہتا ہے کہ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اپنا مقصد واضح کیا ہوگا؟
جواب
اسلام اس لئے نہیں آیا تھا کہ عربوں کے (یا کسی دوسرے کے) رسم و رواج کی پیروی کرے بلکہ وہ اس لئے آیا تھا کہ عربوں سمیت ساری دنیا کی رہنمائی کرے۔پیغمبر اسلامؐ کی بعثت کےقبل عرب میں بہت سے اچھے اور برے رسوم رائج تھے۔ لیکن اسلام نے آتے ہی ایک انقلاب برپا کر دیا۔ان کے تمام قبیح رسوم و عادات کو بالکل جڑ (بنیاد)سے اکھاڑ پھینکااورصرف انہیں دستوروں کو باقی رکھا جو خود اس کی نظر میں مستحسن تھے۔
اگر اسلام عربوں کے جداگانہ نظامِ خانوادگی کو ناپسند کرتا تو اس کے لئے اس طریقہ کا استیصال چنداں دشوار نہ تھا ۔لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے قرآن میں اس کا تذکرہ کرنا اور خاموشی سے گذر جانا اس طرز رہائش پر مہرتصدیق ثبت کرتا ہے۔
10-عملی مثالیں
رسول اکرمؐ اور اہل بیت طاہرین ؑ کی زندگیوں میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کے یہاں بھی جداگانہ خاندان کا طریقہ (اسلامی قیود و شرائط کے ساتھ) رائج تھا۔
سنہ 35 عام الفیل میں مکہ میں قحط پڑا۔حضرت ابوطالبؑ کثیرالعیال تھے۔ رسالت مآبؐ نے یہ محسوس کیا کہ چچا تنگدستی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ حضرت عباسؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا آپ مالدار ہیں ابو طالبؑ کی مدد کیجئے، عباس ؓ راضی ہوگئے۔ دونوں حضرت ابو طالبؑ کے پاس پہنچے اور یہ طے پایا کہ علیؑ رسول ؐ کے سپرد ہوں، جعفرؓ عباس کے گھر جائیں اور عقیل ابو طالبؑ کے پاس رہیں(بحارالانوار، ج۳۸، ص294-295)۔
اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت رسالت مآبؐ اور حضرت ابو طالبؑ دونوں کا نظام خانہ داری علیحدہ تھا۔ اس کے باوجود یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں حضرات(علیہما السلام) کے درمیان اس سے زیادہ محبت و شفقت و احترام پایا جاتا تھا جتنا ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہو سکتا ہے۔اس واقعہ سے جہاں جداگانہ نظامِ خانوادگی کی تائید ہوتی ہے وہاں اسلامی نظام کے دوسرے اہم پہلو سے ’’صلۂ رحم‘‘ پربھی روشنی پڑتی ہے ۔
اپنی زندگی کے آخری ماہ رمضان میں حضرت علیؑ کا یہ معمول تھا کہ ایک روز امام حسن ؑ کےگھر افطار فرماتے تھے، دوسرے روز امام حسین ؑ کے گھر اور تیسرے روز حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر افطار فرماتے تھے(بحارالانوار، ج42، ص224؛ ارشاد مفید،ص7) ۔
یہ روایت بھی اسلامی نظام کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے:
خانہ داری کے علیحدہ انتظامات اور صلۂ رحم۔
یہ دونوں روایتیں مسلمانوں کے گھریلو نظام کےمتعلق ان کی رہنمائی کےلئے کافی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس صراط مستقیم سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ اسلام کی شاہراہ سے بھی الگ ہوجائے گا۔
دوسرا باب: والدین اور اولاد کے حقوق اور ذمہ داریاں
1۔والدین اور اولاد
’’آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً‘‘
’’تمہارے باپ ہو یا بیٹے تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون تمہاری نفع رسانی میں زیادہ قریب ہے ‘‘(سورہ نسا، آیت11)۔
مذکورہ بالا آیۂ مبارکہ والدین اور اولاد کے باہمی تعلقات کے بارے میں اسلامی نظریہ کا بخوبی انکشاف کرتی ہے۔اوائل زندگی میں جبکہ فطرت انسانی طفلی کےمراحل سے گذرتی رہتی ہے وہ ماں باپ ہی کی بے مثال محبت اور توجہ ہوتی ہے جو بچوں کو انتہائی بے بسی اور عاجزی کی منزل سے گذار کر پوری طاقت اور خود اعتمادی کے درجے تک پہنچاتی ہے۔
اس کے بالمقابل ضعیفی کے عالم میں انسان کودک نادان بن جاتا ہے ، اس کا جسم و دماغ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:
’’وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلاٰ يَعْقِلُونَ‘‘
’’ ہم جس کو لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ( کر بچوں کی طرح مجبور کر)دیتے ہیں‘‘(سورہ یس، آیت68)۔
اس وقت اسلام اولاد کو یاد دلاتا ہے کہ:
’’هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلاَّ الْإِحْسٰانُ‘‘
’’بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اوربھی ہے؟ (سورہ رحمن، آیت60)۔
کل انہوں نے تمہاری عاجزی کو سہارا بخشاتھا آج تم ان کی شکستگی کو سنبھالو۔
2۔ حقوق والدین کے بارے میں شدت تاکید کا سبب
یہاں ایک نکتہ قابل غور ہے ہم کو قرآن یا احادیث میں اولاد کی پرورش و نگہداشت اور تربیت و پرداخت کےمتعلق اتنی شدیدتاکیدنظر نہیں آتی جتنی حقوق والدین کا لحاظ رکھنے کے بارے میں پائی جاتی ہے۔آخر ایسا کیوں ہے؟
شارع اسلام نے اپنے اس طرز عمل سے صاحبان بصیرت کے لئے غور و فکر کرنے کی ایک نئی راہ کھول دی ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ انداز ہدایت کتنا مطابق فطرت اور مبنی بر عقل ہے۔
اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین کا دل محبت اولاد کا سرچشمہ ہوتا ہے اور یہ الفت روح حیوانی کے ساتھ ساتھ تمام رگ و پے میں سرایت کرجاتی ہے۔ خود قرآن مجید نے کئی مقامات پر والدین کی اس محبت کی طرف اشارہ کیا ہے ۔
اس کے برخلاف اولاد کو والدین سے اتنی محبت نہیں ہوتی ۔ خصوصاً اس وقت جب اولاد بڑی ہوکر والدین کی توجہ اور تربیت سے مستغنی ہوجائے۔ یہاں بات احترام اورعزت کی نہیں ہو رہی ہے۔یہاں گفتگو ہے اس طرح کی فطری محبت کی جیسی والدین کو اولاد سے ہوتی ہے اور مشاہدہ اس فرق کا شاہد عادل ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ سیدھی شاہرا ہ پر راستہ بتانے والے نشانات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔لیکن اس چوراہے پر جہاں سے مختلف راہیں پھوٹتی ہیں اگر راستہ بتانے والے ان نشانات موجود نہ ہوں (یا کوئی رہنما ساتھ نہ ہو) تو کعبہ کے بجائے ترکستان جانے سے کون بچا سکتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جن امور سے تغافل نہ برتنے پر فطرت خود احتساب کرتی ہے ان کے متعلق مذہب کو زیادہ نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ جہاں سے فطرت کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے وہاں اسلام دستگیری کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور انسان کو یہ بتا کرکہ اب اسے کدھرجانا ہے اور کیا کرنا ہے اسے صحیح راستے پر لگا دیتا ہے۔
اسی لئے شارع اسلام نے حقوق اولاد کے متعلق اتنی زیادہ فہمائش نہیں کی والدین کے حقوق پر بھرپور زور دیا اور تاکید کی ۔اس اجمال کی تفصیل آئندہ آرہی ہے۔
3۔ حقوق اولاد
ارشاد نبویؐ ہوتا ہے کہ:
’’يَا عَلِيُّ يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا‘‘؛ ’’اے علیؑ! والدین پراولاد کے حقوق ویسے ہی لازم ہیں جیسے اولاد پر والدین کے حقوق لازم ہیں۔ (وسائل الشيعة ،ج21 ؛ ص390 و ج21 ؛ ص480. الكافي،ج6 ؛ ص48۔ واضح رہے کہ مذکورہ حدیث اس طرح بھی نقل ہوئی ہے کہ: ’’يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً مُؤْمِناً مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا‘‘؛ (الخصال، ج1 ؛ ص55؛ روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج2 ؛ ص367)۔ البتہ کتاب الخصال میں اولاد کے ’’صالح‘‘ ہونے کے ساتھ ’’مومن ‘‘ہونے کی قید نہیں ذکر ہوئی ہے) ۔
حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہیں۔ اس کا فریضہ دوسرے کا حق ہے۔ اگرچہ والدین کی فطری محبت اولاد کی بہبودی اور پرورش و نگہداشت کی معتبر ضامن تھی ۔اس کے باوجود اسلام نے اس سلسلہ میں جو لائحہ عمل مرتب کرکے ہمیں دیا ہے وہ قابل وجد ہے۔
پیدائش سے لے کر جوانی تک حیات انسانی میں چند ایسے اہم موڑ آتے ہیں جن میں بے سوچےسمجھے ایک قدم بھی بڑھانا دنیااور آخرت کی کامیابی اورخوشی کو برباد کر دیتا ہے۔ ان میں سب سے اہم منزل تعلیم اور اخلاقی تربیت کی ہے ۔آئندہ سطور میں ان دو امور سےمتعلق چند اسلامی ہدایات پیش کی جارہی ہیں جن سے بانیٔ اسلام کے منشا٫اور مرضی کا اندازہ کیا جاسکے گا۔
الف- اچھا نام رکھنا
امیرالمومنین علیؑ نے ارشاد فرمایا:
’’أَوَّلُ مَا يَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمُ اسْمَ وَلَدِهِ‘‘
’’اولاد کے ساتھ انسان کی سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ اسے اچھے نام سے موسوم کرے۔پس تم میں سے ہرشخص کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا عمدہ نام رکھے(الكافي ، ج6 ؛ ص18؛ وسائل الشيعة ، ج21، ص389)۔
یہ حقیقت ہے کہ اچھا نام انسان کےنفسیات پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔بچہ مختلف آدمیوں کی زبان سے اپنا نام دن رات سنتا رہتا ہے اور یہ سمجھنے کے وجوہ موجود ہیں کہ وہ نام جس قسم کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے دماغ کے تحت الشعوری پر دو ںمیں اسی قسم کی صفات کوتقویت پہنچتی ہے۔ کہنےکا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی خراب آدمی کا نام اچھا نہ تھا۔ نہیں! ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ نام انسان کی شخصیت پر ایک معتد بہ (بہت زیادہ)اثر ڈالتا ہے ہے بشرطیکہ ماحول یا تربیت اس اثر کو زائل نہ کر دے۔
خراب نام رکھنے میں ایک اورقباحت ہے ۔جب بھی کوئی اس شخص کو اس نام سے پکارے گا اسے شرمندگی محسوس ہوگی اور نام ایک مستقل کوفت بن کر رہ جائے گا۔یہ مسلسل خلش اسے معاشرہ سے بیزار کرسکتی ہے۔اسی لئے بہت سی احادیث میں اچھا نام رکھنے کے لئے بہت ہی تاکید وارد ہوئی ہے۔
رسالت مآبؐ تو اس کا اتنالحاظ رکھتے تھے کہ امام جعفر صادقؑ نے ارشادفرمایا کیا ہے کہ:
’’ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ؐ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَةَ فِي الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ‘‘
’’ آنحضرت ؐ آدمیوں اور شہروں کے خراب ناموں کو بدل دیا کرتے تھے‘‘(وسائل الشيعة، ج21؛ ص390)۔
اس کی پرزور سفارش کی گئی ہے کہ بچوں کا نام یا تو رسولؐ و آل رسولؑ کے ناموں اور القاب پر مبنی ہویا اس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت اور بچہ کی بندگی ظاہر ہو۔حیرت یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنے بچوں کا نام فلم ایکٹروں اور ایکٹرسوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ یہ ذہنیت اس فکری بیماری کی نشاندہی کرتی ہے جس کی جڑیں ہمارے معاشرے میں راسخ ہوتی جارہی ہیں۔یہ رجحان یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور اپنی طرز فکر میں بانی ٔاسلامؐ اور ان کی آل اطہارؑ سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھے ہیں۔ اب ہماری نظر میں ایسے افراد زیادہ اہمیت اور عظمت حاصل کر چکے ہیں جن کی زندگی اسلامی اصول کے بالکل برعکس بسر ہو رہی ہے۔ اور جو کسب معاش کے لئے حرام اور ناجائز ذرائع اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کے ناموں سے موسوم کر کے ہم ان نونہالوں کوتعلیم دے رہے ہیں کہ ان کو بھی اپنی عملی زندگی میں اسلام اور اس کے ہدایات کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ب۔بچوں اور نوجونواں کی زندگی کے تین دور
بچپن سے لے کر 21۔ 22 برس کے سن تک انسانی زندگی تین حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے:
پہلا دور: پیدائش سے سات برس تک
قدیم حکما٫ نے دماغی نشوونما کا مطالعہ کرکے یہ رائے قائم کی کہ رضاعت(دودھ پینے کے زمانے) کےبالکل ابتدائی دنوں میں انسانی عقل بالکل سادہ ہوتی ہے اور ہر قسم کے ادراکات سے معرا(خالی) رہتی ہے۔پھر آہستہ آہستہ وہ بدیہیات اور پیش پا افتادہ چیزوں کا ادراک کرنے لگتی ہے۔اور اسم کو مسمی کے ساتھ مربوط کرنے لگتی ہے۔مگر ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ عقلی دلیلوں اور نظریات کا بار برداشت کرسکے۔ ان حکما٫ نے ان تدریجی ترقیوں کے لئے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی تھی اور واقعاً کوئی قطعی تعیّن بہت ہی دشوار ہے ۔مگر موجودہ حکما٫ اور فلاسفہ نے مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پریہ رائے قائم کی ہے کہ عموماً بچوں کا دماغ سات آٹھ برس کی عمر تک اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر کتابی تعلیم کا بوجھ ڈالا جائے ۔اور جو بچے اس ننھی سی عمر میں کتاب رٹنےکے لئے بٹھا دئیے جاتے ہیں ان کی دماغی صلاحیت مرجھا کر رہ جاتی ہے اور وہ مضرتقلید کا شکار ہوکر اپنی ذاتی عمر کھو بیٹھتے ہیں۔
دوسرا دور: آٹھ برس سے چودہ برس تک
اب دوسرا دور آتا ہے جس میں دماغ معقولات ونظریات کا استقبال کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے۔تعلیمی شوق کے شباب کا یہی دور ہے جب کہ ہر چیز کی کنہ(گہرائی) اور لِمْ (علت)معلوم کرنے کی دھن چھائی رہتی ہے۔اس زمانے میں دماغ جس طرح تروتازہ ہوتا ہے اورجیسی صلاحیتِ تعلیم اس دور میں ملتی ہے پھر نظر نہیں آتی۔اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جذبۂ تجسس جو انسان کو نامعلوم وادیوں کی طرف قدم بڑھانے پر اکساتا ہے پوری طرح آزاد ہوتا ہے اور علائق دنیاوی اور مختلف قسم کی ذمہ داریاں پاؤں کی زنجیر نہیں بنتیں۔
تیسرا دور: چودہ پندرہ برس کے بعد
چودہ پندرہ برس کے بعد عقل ایک حد تک پختہ ہوجاتی ہے ابتدائے بلوغ کا دور نگاہ کے سامنے نئے افق کھولتا ہے۔جنسی جذبہ، شادی، گھریلو زندگی اور اس کے پیچیدہ مسائل پر غور و خوض سے شروع ہو جاتا ہے چونکہ تاہلی(ازدواجی) زندگی بسر کرنے کی منزل روزبروز قریب آتی جاتی ہے اس لئے سودائے مستقبل اورکل کی فکر ہر وقت دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ کل جو بچہ تھا اب جوان کہلاتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بہت جلد اسےاپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہےکیونکہ ہرگزرتا ہوا دن اسے اس منزل سے قریب کر رہا ہے جہاں ایک خانوادہ کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ جائیں گی۔
یہ خیالات اس کو کسب معاش کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لئے مہمیز(آمادہ)کرتے ہیں اور وہ اس کےلئے کسی مناسب طریقہ کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔
ان تشریحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ احادیث معصومینؑ پر نظر ڈالیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ نفسیات کےجن اسرار کا انکشاف ماہرین علم النفس نے سینکڑوں تجربات کے بعد کیا ہے انہیں یہ حکمائےربانی چودہ سو برس پہلے کس طرح بیان کر گئے ہیں جیسے یہ باتیں ان کے لئے اجلی البدیہات(بالکل روشن) تھیں۔
(۱) حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا کہ:
’’ دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ‘‘۔
’’اپنے بچے کو سات برس چھوڑ دو کہ کھیلتا رہے (یہ پہلا دور ہے) اور سات برس اپنی نگرانی میں رکھو (یہ تعلیم و تربیت کا دوسرا دور ہے )پس اگر اس عرصے میں وہ فلاح پا جائے تو بہتر ہے ورنہ سمجھ لو کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے‘‘۔(وسائل الشيعة ؛ ج21؛ ص473 الكافي ، ج6 ؛ ص46)۔
(۲) حضرت رسالت مآبؐ نے ارشاد فرمایا:
’’اَلْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ رَضِيتَ خَلَائِقَهُ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ إِلَّا ضُرِبَ عَلَى جَنْبَيْهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ‘‘۔
“لڑکا سات برس تک سردار ہے اورپھرسات برس تک غلام ہےاور پھرسات برس تک وزیر ہے۔پس اگر اکیس برس کے اندر اس کی عادتیں پسندیدہ بن گئیں تو خیرہے ورنہ اسے اس کی راہ چھوڑ دو کیونکہ تم نے خدا کی بارگاہ میں اپنا عذرتمام کر دیا”(وسائل الشيعة ، ج21 ، ص476)۔
چونکہ کھیل کود کا زمانہ بے فکری کا ہوتا ہے اس لئے اسے ’’سرداری‘‘ کا زمانہ کہا گیا ہے اورتعلیم و تربیت میں والدین اور اساتذہ کا پابندرہنا پڑتا ہے اس لئے اس کی تعبیر ’’غلامی‘‘ سے کی گئی ہے اور تیسرے دور میں چونکہ کسب معاش کے سلسلے میں باپ کا ہاتھ بٹانے کی امید کی جاتی ہے اس لئے ’’ وزیر‘‘ کی لفظ استعمال کی گئی ہے۔
ان میں سے ہر دور کے متعلق شریعت اسلامیہ نے دستور العمل بنائے ہیں۔
ج۔ تینوں مراحل کے متعلق ہدایات
الف۔ پہلے دور کے متعلق ہدایات
یہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ پہلے دور میں دماغ کتابوں کا بار برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک دماغ معطل رہتا ہو۔بلکہ وہ غیرشعوری طور پر ہر وقت ماحول سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت اور اٹھان پر کامل توجہ مبذول رکھی جائے۔
خود بچوں کے ساتھ مہذبانہ برتاؤ تہذیب و اخلاق سکھانے کا سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ اس طرح بچے آداب مجلس، عمدہ اخلاق اور شریفانہ برتاؤ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔رسالت مآبؐ نے ارشاد فرمایا ہے:
’’أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُمْ‘‘۔
’’اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ ، خدا تمہیں بخش دے گا‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص476)۔
اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ بچوں کو اچھے ماحول میں رکھا جائے رسالتمآب ؐ نے ارشاد فرمایا ہے:
’’يَا عَلِيُّ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ يَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحا‘‘۔
’’اےعلیؑ !باپ پر اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ․․․ اس کو اچھے آداب سکھائے اور اسے موضع صالح( اچھی جگہ) میں رکھے ‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص389-390)۔
اسی سلسلے میں اسلام نے یہ چاہا ہے کہ ہنستے کھیلتے آہستہ آہستہ بچوں کی مذہبی تربیت بھی ہوتی رہے کیونکہ بچوں کے سادہ اذہان پر جونقوش کمسنی میں ابھر آتے ہیں ان کو بعد میں مٹانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر اس عمر میں ان کے ذہنوں پر مذہب کا احترام اورمحبت ترسیم ہوجائے تو بچے ہمیشہ مذہب سے وابستہ رہیں گے۔
مندرجہ ذیل روایت اس دور میں مذہبی تربیت کا نصاب یوں معین کرتی ہے:
عن عبداللہ بن فضال عن احداھماؑ: ’’إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ يَوْماً فَيُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيُّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيَّهُمَا شِمَالُكَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ صَلَّى وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعٌ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَ عُلِّمَ الصَّلَاةَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ‘‘۔
عبداللہ بن نے فضال پانچویں یا چھٹے امام (علیہما السلام) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ’’ جب لڑکا تین برس کا ہو جائے تو اس سے سات مرتبہ کہا جائے کہ: ’’لا الہ الا اللہ‘‘ کہو۔ پھر اسی حال پر چھوڑ دیا جائے،یہاں تک کہ تین برس سات مہینہ بیس دن کا ہو جائے، اس وقت سات مرتبہ ’’محمد الرسول اللہ‘‘ کہنا سکھایا جائے۔پھر چھوڑ دیا جائےیہاں تک کہ پورے چار سال کا ہوجائے اس وقت سات مرتبہ’’صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد‘‘ کہلوایا جائے۔پھر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ پانچ برس کا ہو جائے،اس وقت پوچھا جائے کہ ’’تیرا دایاں ہاتھ کونسا ہے اور بایاں کونسا ہے؟‘‘ جب یہ پہچان لے تو اس کو قبلہ رخ کر کے ’’سجدہ ‘‘ کا حکم دیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے ۔یہاں تک کہ چھ برس پورے ہو جائیں اس وقت اس سے ’’نماز‘‘ پڑھنے کو کہا جائےاوررکوع وسجود سکھایا جائے۔جب سات سال پورے ہو جائیں تو اس سے کہا جائے کہ ’’چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوکرنماز پڑھو ‘‘۔پھر اسی حال پر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ پورے نو برس کا ہو جائے۔اس وقت اس کو باقاعدہ وضو سکھایا جائے اور اس (کےترک)پر مارا جائے اور باقاعدہ نماز سکھائی جائے اور اس (کےترک) پر مارا جائے ۔پس جب وہ اس طرح وضواورنماز سیکھ لے گا تو خدا اس کے والدین کو بخش دےگا‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ، ص474)۔
اس روایت کا ایک ایک فقرہ قابل غور ہے کیونکہ تدریجی طور پر بچوں کو شریعت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے ۔بغیر اس کے کہ ان کے ذہنوں پر بےجا دباؤ ڈالا جائے ۔ویسے بچوں کو دس بارہ سال کی عمر میں بھی تین چار دن کی توجہ میں وضو اور نماز سکھائی جا سکتی ہے لیکن اس تعلیم سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جو زمانۂ طفلی کی اس زینہ بہ زینہ تربیت میں مضمر ہیں۔
ب۔ دوسرےدور کے متعلق ہدایات
اب باضابطہ تعلیم کا دور شروع ہوتا ہے۔منازل حیات میں یہ سب سے اہم منزل ہے جو مستقبل کا سنگ بنیاد ہے۔اسلام بتاتا ہے کہ اس دور میں پہلے بچوں کو بقدر واجب دینی تعلیم دی جائے تاکہ وہ اعتقاد اور عمل میں گمراہیوں سے محفوظ رہ سکیں۔
امام صادقؑ ارشاد ہے:
’’بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرْجِئَة‘‘؛ ’’ اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دینے میں جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ مرجئہ (ایک گمرہ فرقہ)تم سے پہلے ان تک پہنچ جائیں ‘‘(الكافي، ج6، ص47۔ واضح رہے کہ بعض مقامات پر ’’حدیث‘‘ کی جگہ لفظ’’احکام‘‘ بھی آیا ہے)۔
مقصد یہ ہے کہ الحاد و بے دینی سکھانے والے درسی نصاب کا اثر دماغ پر چھا جائے اس سے پہلے انہیں دین و مذہب میں راسخ(مضبوط) کردو۔ بچے ہری ٹہنی ہوتے ہیں جدھر موڑا جائے گا مڑجائیں گے۔اگر اس کی عمر میں انہیں مذہبی تعلیم سے بے بہرہ رکھا گیا تو پھر نام نہاد ’’غیر مذہبی‘‘ (اورحقیقتا کافرانہ) نظام تعلیم کے زہریلے اثرات سے انہیں خدا ہی بچائے تو بچائے آئے۔
افسوس ہے کہ ہم آج اس ہدایت سے غافل ہوگئے ہیں۔ایک زمانہ تھا جب بچوں کے لئے قرآن مجید اور مذہبیات کی ابتدائی تعلیم لازمی سمجھی جاتی تھی ۔مگر وائے بر حال ما کہ آج ہمارے بیشتر نونہال سن شعور تک پہنچتے پہنچتے ایسی درسگاہوں میں داخل کر دیئے جاتے ہیں جہاں ان کے دماغ پر شب و روز مخالف مذہب پروپیگنڈا کا اثر غیر محسوس طور پر پڑتا رہتا ہے۔اور یہی بیج عمرکے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے لا مذہبیت کا تناور درخت بن جاتا ہے۔
ایام جوانی میں مجھے سادات کی ایک بستی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ اچھے خاصے عمر رسیدہ افراد اصول دین کی تعداد اور ائمہ معصومینؑ کے اسمائے گرامی تک سے واقف نہیں۔ طول و عرض ہند وپاک میں کتنی بستیاں ایسی ہوں گی، یہ تصور انسان کو لرزہ براندام کر دیتا ہے۔خداوندکریم ان حضرات اور ان اداروں اور تنظیموں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو بچوں کی دینی تعلیم کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔
بانیٔ اسلام نے لڑکوں کی تعلیم کے لئے دو باتوں پر زور دیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:
’’حَقُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ إِذَا كَانَ ذَكَراً ․․․ وَ يُعَلِّمَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَ يُطَهِّرَهُ وَ يُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ‘‘۔
’’ لڑکے کا حق باپ پر یہ ہے کہ․․․ اسے کتاب خدا کی تعلیم دے اور تیرنا اورشہسواری سکھائے(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص481)۔
امام صادق ؑ کا ارشاد ہے کہ باپ کا فریضہ ہے کہ:
’’․․․ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ ․․․‘‘؛ ’’․․․لڑکے کو لکھنا سکھائے ․․․‘‘( وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص482)۔
ان روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینیات،فنون جنگ اور کتابت کو لڑکوں کے نصاب تعلیم میں لازمی طور پر شامل کرنا چاہئے۔ ان مضامین کے علاوہ جو معلوم لڑکے کی افتاد طبع سے مناسبت رکھتے ہوں یا کسب معاش کے لئے ضروری ہوں ان کو بھی سکھانا چاہئے۔دوسرے لفظوں میں، یہ تینوں چیزیں لازمی مضامین کی حیثیت رکھتی ہیں اور بقیہ علوم اختیاری ہیں۔
لڑکیوں کے لئے الگ نصاب مقرر کیا گیا ہے مذکورہ بالا حدیث نبوی ؐ کا تتمہ یہ ہے:
’’وَ إِذَا كَانَتْ أُنْثَى أَنْ ․․․يُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ- وَ لَا يُعَلِّمَهَا سُورَةَ يُوسُفَ وَ لَا يُنْزِلَهَا الْغُرَفَ‘‘۔
’’اگر اولاد لڑکی ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ․․․ اسے سورہ ٔنور کی تعلیم دے، سورۂ یوسف نہ پڑھائے اور اسے چھت پر نہ جانے دے‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص481)۔
اس روایت کا ماحاصل دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ چراغ خانہ بنیں، شمع محفل نہ بن جائیں۔اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو تعلیم بھی انہیں دیں گے جائز ہوگی۔
البتہ حصول علم کے لئے بھی حجاب کی پابندی ضروری ہے اورتعلیم کے لئے ایسے سبجکٹ(Subject) انتخاب کئے جائیں جن میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو۔
ج ۔ تیسرے دور کے متعلق ہدایات
تیسرا دور کسب معاش اور اس کی تیاریوں کا دور ہے۔ لیکن اسے فی الحال یہاں بیان کرنے کا محل نہیں ہے۔
اسی دور میں اولاد کی شادی کا وقت آتا ہے۔اس کے متعلق بھی شریعت نے ہدایات دی ہیں۔خصوصاً لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرنے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے۔رسالتمآب ؐ کا ارشاد ہے کہ لڑکی کا حق باپ پر یہ ہے کہ:
’’وَ يُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا‘‘۔
’’ اسے شوہر کے گھر رخصت کرنے میں جلدی کرے‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص481)۔
بے حد رنج ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے مسلمان (اور بالخصوص ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان) اس ذمہ داری کے سلسلے میں بہت ہی بے توجہی اور لاپرواہی بھرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی لڑکیاں 35- 40 برس کی ہو جاتی ہیں اور اس وقت کوئی شخص ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ شادی میں تاخیر کے نقصانات اظہر من الشمس ہیں اور ہرشخص اس غیر ذمہ دارانہ پدری رویہ کی برائیوں کو محسوس کرتا ہے۔مگر جھوٹا جذبۂ تفوّق ایسے ماں باپ کو اس حقیقت سے غافل کئے رہتا ہے۔یہ تفوّق کا احساس کیوں پیدا ہوتا ہے؟یا تو مالی برتری کا احساس ہوتا ہے یا ذات اور خاندان کی برتری کا گھمنڈ ہوتا ہے؟۔ ان دونوں چیزوں کے گھمنڈ کی قربان گاہ پر بیٹیوں کی زندگی قربان کر دی جاتی ہے اور وہ ’’بوڑھی کنواریاں‘‘ بن کر رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے کہ اگر نوجوان مومن کا پیغام آئے جو اخلاق اور سیرت اور مذہب کی پابندی کے لحاظ سے قابل اعتماد ہو تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائےاگرچہ وہ مالی اور خاندانی لحاظ سے لڑکی کے والدین کا ہم پلہ نہ ہو۔ رسالتمآبؐ کا ارشاد ہے کہ:
’’الْمُؤْمِنُ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ كُفْوُ الْمُسْلِمَة‘‘۔
’’ہر مومن، مومنہ کا کفو ہے اور ہر مسلمان، مسلمہ کا کفو ہے ‘‘(وسائل الشيعة ، ج20 ؛ ص67-68) ۔
مگر ہندوؤں کے ذات پات کے تمدن نے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ پر ایسا تسلط حاصل کر لیا ہے کہ ہم اپنے روشن اسلامی تمدن و تہذیب کو خود حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ خدا رحم کرے۔
مذکورہ بالا حدیث میں لڑکوں کے متعلق یہ ملتا ہے کہ:
’’وَ يُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ‘‘
’’جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص482)۔
مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لڑکا پندرہ برس کا ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کر دی جائے خودرسالتمآبؐ کا پہلا عقد 25 برس کے سِن میں ہوا تھا۔ اسی طرح امیر المومنین ؑ کاعقدبھی 25 برس کی عمر میں ہوا تھا۔مگر یہ بھی کوئی قاعدۂ کلیہ نہیں ہے۔اس کا اصول صرف یہ ہے کہ جب انسان میں جذبات شباب پختہ ہو جائیں اور اس میں متاہلانہ زندگی بسرکرنے کی طرف رغبت پیدا ہو جائے اس وقت اس کی شادی بلاتاخیر کر دی جائے۔ یہ وہ معیار ہے جس کے لئے نہ عمر کی تعیین کی جاسکتی ہے اور نہ سِن کی قید لگائی جاسکتی ہے۔
اس منزل پر پہنچ کر اولاد کے متعلق والدین کی اہم ذمہ داریاں ختم ہوجاتی ہیں۔اگر کوئی شخص ان شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اولاد کی پرورش کرے اور کامیاب ہو جائے تو یقیناً اولاد راحتِ دل اور خنکیٔ چشم بنے گی اور ایسی ہی اولاد کےمتعلق رسالتمآبؐ نے ارشاد فرمایا ہے:
’’الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ‘‘۔
’’صالح اولاد جنت کے پھلوں میں سے ایک پھول ہے‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص358)۔
نیزانہیں حضرت ؐ نے فرمایا ہے :
’’مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ اَلْوَلَدُ الصَّالِحُ‘‘۔
’’صالح اولاد انسان کی ایک سعادت ہے‘‘(وسائل الشيعة ، ج21 ؛ ص359)۔
۳۔حقوق والدین
حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’بِعِزَّتِی وَ جَلاَلِی وَ ارتِفَاعِ مَکَانِی، لَو أنَّ العاقَّ لوالدَیه تاتی بِأعمالِ الأنبیآء جمیعاً لَم أقبَلهَا مِنه‘‘۔
’’مجھے اپنے عزت و جلال اور رفعت شان کی قسم ہے کہ اگرعاق والدین میرے پاس تمام انبیاء کے اعمال لے کر آئے تو بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا‘‘(انوار الہدایۃ؛ بحارالانوار، ج۷۴، ص ۸۰)۔
اولاد جیسے جیسے جوانی کی طرف قدم بڑھاتی ہے والدین ضعیفی کی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ماں باپ کی محبت اور شفقت اولاد کی پرورش اور تربیت میں ان کی زحمتوں کا لازمی اور فطری تقاضا یہ ہے کہ اولاد والدین کی اطاعت اوراعانت میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔
اس عالم اسباب میں والدین ہی اولاد کے وجود کی علّت ہوتے ہیں، وہی اس کی حفاظت اور بقاء کے لئے جدوجہد کرتے ہیں، وہی اس کو درجۂ کمال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لئے کسی امکانی کوشش سے دریغ نہیں کرتے۔ خدائے واحد و یکتا کے بعد اگر انسانی زندگی، بقا اور کمال کسی کا مرہون منت ہے تو وہ والدین کی ذات ہے۔دوسروں لفظوں میں والدین ہمارے ’’ربِّ مجازی‘‘ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کئی آیتوں میں خدا کی عبادت اور والدین کی اطاعت کو پہلو بہ پہلوذکر کیا ہے:
’’وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لاٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً‘‘۔
’’اللہ کی عبادت کرو اور کسی کواس کا شریک نہ قرار دو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو‘‘(سورہ نسا، آیت36)۔
’’وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً‘‘۔
’’اور تیرے رب نے یہ حکمِ محکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو ‘‘(سورہ اسرا، آیت23) ۔
۴- حقوق کے والدین کا تجزیہ
میں نے جہاں تک غور کیا ہے والدین کی ربوبیت کو ہرعمرمیں خدا کی ربوبیت کا آئینہ دار پایا ہے۔بچہ کی پیدائش ہویا رضاعت،نگہداشت ہو یا تربیت۔ ہرمنزل میں ماں باپ ہی وہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالی کا فضل و انعام بچہ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح حقوق کی نوعیت میں بھی بہت کچھ مشابہت پائی جاتی ہے ۔
خداوندعالم کے حقوق کی تین قسمیں قرار دی جاسکتی ہیں:
اؔوّل وہ حقوق جو ’’نفس‘‘سے متعلق ہیں۔ مثلاً معرفت باری ۔
دؔوسرےوہ حقوق جو ’’جسم‘‘سے متعلق ہیں۔ مثلاً نماز اور روزہ وغیرہ ۔
تؔیسرے وہ حقوق جو ’’مال‘‘ سے متعلق ہیں۔ مثلاً زکوۃ اور خمس وغیرہ ۔
حقوق والدین کی بھی بعینہ یہی تین قسمیں قرار دی جاسکتی ہیں:
آئیے پہلے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت پر نظر ڈالیں (جس کے ساتھ امام جعفر صادق ؑ کی بیان کردہ تفسیر قوسین کے درمیان درج کی گئی ہے):
’’وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً إِمّٰا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ كِلاٰهُمٰا فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلاً كَرِيماً۔ وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمٰا كَمٰا رَبَّيٰانِي صَغِيراً ‘‘(سورہ اسرا، آیت23و24)۔
’’اور تیرے رب نے یہ حکمِ محکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو (ان سے اچھا سلوک کرو اور انہیں اس بات کی زحمت نہ دو کہ اپنی احتیاج تم سے بیان کریں بلکہ اس کے قبل ہی ان کی ضروریات کو پورا کر دو اگر چہ فی الحقیقت وہ تم سے مستغنی ہوں) اور تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائیں ( اور تم پر خفا ہوں) تو ان سے ’’اف‘‘ تک نہ کرو اور (اگر تمہیں ماریں تو) انہیں مت جھڑکو (بلکہ ایسے موقع پربھی)ان سے اچھے طریقے سے بات کرو (یعنی یہ کہو کہ خدا آپ لوگوں کو بخشش دے)اور ان کے سامنے رحمت کے ساتھ خاکساری کا پہلو اختیار کرو (اور ان پر جب بھی نظر کرو نرمی اور رحم رحمت کے ساتھ دیکھو۔ نہ تو اپنی آواز ان کی آواز پر بلند کرو ،نہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اونچا کرو اور نہ ان کے آگے قدم بڑھاؤ )اور یہ کہا کرو کہ: اے پالنے والے! جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما‘‘(وسائل الشيعة ؛ ج21 ؛ ص488؛ الكافي ، ج2 ؛ ص158)۔
اس تفسیر نے حقوق کے والدین کی تینوں قسموں کی تشریح کر دی ہے۔اور ذرا سا غور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ:
والدین کی سختیوں کو برداشت کر لینا، گفتگو میں نرمی اور آہستگی سے کام لینا، ان پر پیش قدمی نہ کرنا،اوراپنا ہاتھ اور اپنی آواز ان کے ہاتھ اور ان کی آواز پر بلند نہ کرنا یہ سب حقوق جسمانی اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں۔
اور ان کی طرف رحمت اور مہربانی سے دیکھنا اور ان کے لئے ہمیشہ استغفار کر تے رہنا قلبی محبت کا آئینہ دار ہے۔
اور ان کے کہنے سے پہلے ان کی حاجتوں کو پورا کر دینا مالی حقوق سےتعلق رکھتا ہے۔
اس طرح رب حقیقی اور ان ارباب مجازی کے حقوق کی مشابہت نقطۂ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اب میں روایات کی مدد سے کچھ مزید تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس روایت مبارکہ میں پہلے مالی حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد محبت و اطاعت کے حقوق کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس لئے میں بھی اولاً مالی حقوق کی تشریح کروں گا اس کے بعد محبت اور اطاعت کا ذکر کروں گا۔
۵۔ والدین کی ذات باری سے مشابہت مالی حقوق کے لحاظ سے
الف: پہلی مشابہت
رب حقیقی کے قبضہ میں صرف انسان اور اس کی دولت نہیں بلکہ ساری دنیا ہے۔ اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ انسانی دولت کے کسی حصے کا اپنے نام پر مطالبہ کرے۔پھربھی اس مالک نے بہ طور خراج اس دولت کا ایک حصہ اپنے لئے مقرر فرما دیا ۔لہذایہ ضعیف البنیان ارباب مجازی تو واقعاً اس کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی کمائی سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور ان کو بھی اپنے لگائے ہوئے باغ کے ثمرات سے بہرہ یاب ہونے کا حق دیا جائے۔اگر ان کو اس کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی ان کی مجازی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کی خدمت میں اپنے طور پر خراج عقیدت پیش کرے ۔اسی لئے امام جعفر صادقؑ نے(مذکورہ تفسیر میں) ارشاد فرمایا ہے کہ ’’ان کی مالی اعانت کرو اگرچہ وہ تم سے مستغنی ہوں‘‘۔
ب: دوسری مشابہت
باوجود یکہ خداوند تعالیٰ کو ہر انسان سے مالی خراج کے مطالبہ کا حق حاصل ہے لیکن اس نے اپنی رحمت سے اس خراج کو صرف انہیں لوگوں پر واجب کیا ہے جن کے پاس مال کی ایک خاص مقدار موجود ہو۔اور باقی سب کے لئے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو ایک استحبابی امر قرار دے کر جذبۂ عبودیت کے امتحان کا ایک وسیع میدان پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو بالعموم ہرشخص کو والدین کی مالی اعانت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:
’’قُلْ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‘‘۔
’’ اے رسولؐ ! ان لوگوں سے کہئے کہ جو مال بھی تم رضائے الہی کیلئے خرچ کرو اس کے اولین حقدار تمہارے ماں باپ ہیں ان کے بعد دوسرے اقارب وغیرہ (سورہ بقرہ، آیت215)۔
’’وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ إِحْسٰاناً‘‘۔
“اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت کی”(سورہ احقاف، آیت15)۔
لیکن یہ نفقہ واجب اس وقت ہوتا ہے جب اولاد کو اتنی گنجائش ہو کہ اپنے اور اپنی زوجہ کے ضروری اخراجات پورا کرنے کے بعد بھی ان کی اعانت کرسکےنیزؔ والدین میں اعانت کے محتاج بھی ہوں۔اور اگر ان دونوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگئی تو والدین کا نفقہ واجب نہ رہےگا۔
لیکن وجوب کے ساقط ہوجانے کے بعد بھی تاکیدی استحباب اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اسی لئے امام جعفر صادق ؑ نے فرمایا ہے کہ:
’’لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْر‘‘۔
“یہ نفقےثروت اور غربت دونوں حالتوں میں لازم ہیں”(وسائل الشیعۃ ، ج21 ؛ ص515)۔
اس کے علاوہ والدین کو آرام پہنچانے کے سلسلے میں جتنی تاکید وارد ہوئی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور کوئی نتیجہ نکالا ہی نہیں جا سکتا۔
ج: تیسری مشابہت
عبادت الہی خیروبرکت کے نزول کا ایک اہم وسیلہ ہے۔حضرت نوح ؑ نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی تھی :
’’اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً-يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً‘‘۔
’’اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے تم پر آسمان سے موسلادھار با پانی برسائےگا اور مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغ بنائے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا‘‘(سورہ نوح، آیت10-12)۔
اسی طرح خداوندعالم نے والدین کے صلہ اور ان کی مالی اعانت کو بھی وسعت رزق اور طول عمر کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ تنگ دست اولاد کم از کم وسعت رزق ہی کی تمنا اور امید میں خود اپنی خوشی سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی رہے۔ رسالتمآبؐ نے ارشاد فرمایا ہے:
’’مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ أَبَوَيْهِ فَإِنَّ صِلَتَهُمَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ‘‘۔
’’جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور رزق کشادہ کر دیا جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ صلۂ رحم کرے کیونکہ ان کا صلہ خدا کی اطاعت کا ایک حصہ ہے‘‘(بحار الانوار ، ج71 ؛ ص85)۔
اسی مضمون کی ایک اور روایت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے جس میں طول عمر کے بجائے جان کنی کی سہولت کا ذکر ہے۔ اور بے شک خدا کے سب وعدے برحق ہیں۔
۶۔ حق محبت کے لحاظ سے
اس موضوع پر کچھ لکھنے سےقبل یہ عرض کردوں کہ ہمارے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ رسول و آل رسول(علیہم الصلوۃ والسلام) کی محبت خدا کی محبت کا ایک جزو ہے۔اسی اصول کی بنیاد پر میں یہاں پر بہ راہ راست محبت خدا سےمشابہت دکھانے کے بجائے ایسی روایتیں پیش کرتا ہوں جن سے والدین کی محبت اہل بیتؑ کی محبت کے پہلو بہ پہلو نظر آئے گی۔
الف: پہلی مشابہت
شیعہ اور سنی دونوں کی مسلمہ حدیثوں کےمطابق حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب ؑ کا دشمن یا تو منافق ہوگا یا ولدالحرام۔
حضرت جابربن عبداللہ انصاری ؓ فرمایا کرتے تھے :
’’يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى حُبِ عَلِيٍّ (ع) فَمَنْ أَبَى فَانْظُرُوا فِي شَأْنِ أُمِّهِ‘‘۔
’’اے گروہ انصار! اپنی اولاد کو محبت علیؑ کی تعلیم دو ۔اور جو انکار کرے اس کی ماں کے حالات کی جانچ کرو‘‘(بحار الانوار ، ج39 ؛ ص300)۔
حضرت جابر کا یہ ارشاد حدیث نبوی ؐ سے ماخوذ ہے(انوار الہدایہ، جامع الاخبار، فصل 40)۔
اب والدین کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسےبھی سن لیجئے :
’’مَنْ ضَرَبَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ وَلَدُ الزِّنَاء‘‘۔
’’جو اپنے والدین کو مارے وہ ولد الزنا ہے‘‘(جامع الاخبارشعيري، ص84)۔
ب: دوسری مشابہت
جناب سیدہ (صلوات اللہ علیہا) کی شان میں یہ روایت مسلّم بین الفریقین ہے:
’’فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ‘‘۔
’’فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی‘‘(مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج3 ؛ ص332)۔
بعینہ اسی طرح والدین کے متعلق ارشاد رسولؐ ہے:
’’من اذی ابویہ فقد اذانی و من اذانی فقد اذی اللہ و من اذی اللہ فھو ملعون فی التوراۃ و الانجیل و القرآن‘‘۔
’’جس نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی وہ تورات و انجیل و زبور وقرآن میں معلون ہے‘‘(انوار الہدایۃ)۔
اسی طرح رسالتمآبؐ نے اپنے کو اور امیرالمومنینؑ کو اس امت کا باپ کہا ہے:
’’أَنَا وَ عَلِيٌ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّة‘‘۔
’’میں اور علیؑ امت کے دو باپ ہیں‘‘(بحار الانوار ، ج16 ،ص95)۔
شاید اس تشبیہ کی یہ غرض بھی ہو کہ امت والدین کی عظمت کو اچھی طرح سمجھ لے ۔
بہرحال ان تمام روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت والدین بھی محبت الہی کا ایک جزو ہے اورجس طرح اہل بیت رسول (علیہم السلام) سے سرتابی کرنے والا خدا کا دشمن اور جنت سے محروم ہے اسی طرح والدین کو اذیت پہنچانے والا بھی خدا کا دشمن اور جنت سے محروم ہے۔
۷۔ حق اطاعت کے لحاظ سے
الف: پہلی مشابہت
محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہیں۔ اگر دل میں محبت کی شمع روشن ہو تو یہ ناممکن ہے کہ اعضاءوجوارح پر نورِ اطاعت کا پرتو نہ پڑے۔محبت و وفاداری کی مؤثر نصیحت و تلقین کے بعد وہ منزل آ جاتی ہے کہ اولاد کی توجہ والدین کی طرف موڑ دی جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس منزل پر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا آئینہ دار بنادیا ہے۔ یہاں ان آیتوں کے علاوہ جن کو ابتدائے کلام میں ذکر کر چکا ہوں قرآن مجید کا یہ ارشاد بھی قابل غور ہے :
’’إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ ‘‘۔
’’اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا اور دوسرے گنہگاروں میں سے جس کو چاہے بخش دے گا(سورہ نسا٫، آیت48)۔
بعینہ اسی طرح والدین کے سلسلے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے :
’’قل للبارّ بوالدیہ اعمل ما شئت فلن تدخل النار ابدا و قل العاق بوالدیہ اعمل ما شئت فلن تدخل الجنۃ ابدا‘‘۔
’’(اےرسولؐ ) والدین کی اطاعت کرنے والے سے کہہ دیجئے کہ جو تیرا جی چاہے کر کیونکہ تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جا سکتا اور والدین کی نافرمانی کرنے والے سے کہہ دیجئے کہ تو جو عمل بھی کرے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا‘‘(انوار الہدایہ؛ بحارالانوار، ج74، ص74) ۔
(اسی طرح کی ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ: لِيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ جو شخص اپنے والدین کا عاق ہو وہ چاہے جو کام انجام بھی کرلےہرگز جنت میں نہیں جاسکتا ہے(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص ۱۹۶ بحوالہ قطب راوندی، لب اللباب)۔
لیکن اتنا فرق یاد رکھنا چاہئے کہ چونکہ خداوندعالم کی ذات اقدس ہر حاکم سے بالاتر ہے لہذا اس کے احکام کبھی کسی کے حکم سے رد نہیں کئے جا سکتے اور والدین کی حکومت چونکہ حکم خدا پر مبنی اور امر الہی کے تابع ہے اس لئے اگر کسی موقع پر ان کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرائے تو اسے حسن وخوبی سے ٹال دینا پڑے گا، ارشادباری تعالی ہے:
’’وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلىٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ أَنِ اُشْكُرْ لِي وَ لِوٰالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ -وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ عَلىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً‘‘۔
’’ اور ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی۔اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہہ کے اسے پیٹ میں رکھا اور دوسال میں اس کی دودھ بڑھائی کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی اور میری ہی طرف (تم سب کو) پلٹ کر آنا ہے ۔اور اگر وہ دونوں تم سے اس لئے جھگڑیں کہ تم ایسی چیزوں کو میرا شریک قرار دو جن کے متعلق تمہیں کچھ علم بھی نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو البتہ دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے بسر کرو‘‘(سورہ لقمان، آیت14-15)۔
مندرجہ ذیل روایات کو اسی آیت کی تفسیرسمجھنا چاہیے کہ:
’’إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ فَمَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُزَكِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتَهُ وَ أَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ فَمَنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ‘‘۔
امام رضا ؑ نے فرمایا کہ پیغمبرؐ نےفرمایا ہے کہ :
’’اللہ عزو جل نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور انہیں تین دوسری چیزوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اس نے نماز اور زکوۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے اگر کوئی نماز پڑھےاور زکاۃ نہ دے تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی ۔اور اس نے اپنے شکر اور والدین کے شکر کا ایک ساتھ حکم دیا ہے اس لئے اگر کوئی والدین کا شکر ادا نہ کرے تو اس نے اللہ کا شکربھی ادا نہ کیا ۔اور اس نے تقوائے الہی اور صلۂ رحم کا حکم ایک ساتھ دیا ہے اس لئے اگر کسی نے صلۂ رحم نہ کیا تو اس نے خدا کا خوف بھی نہ کیا‘‘(عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج1 ؛ ص258؛ بحار الانوار ، ج71، ص68)۔
اسی طرح امام جعفرصادق ؑ نے ارشاد فرمایا ہے :
’’ثَلَاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِيهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ‘‘۔
’’تین چیزیں جن کوخدائے عزو جل نے کسی بندےکو کسی حال میں چھوڑنےکی اجازت نہیں دی ہے؛ امانت کو اس کے مالک تک پہنچانا چاہئےوہ (مالک) نیکوکار ہو یا بدکار۔ وعدےکو پورا کرنا خواہ جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہے وہ خودنیکوکار ہوں یا بدکار(وسائل الشيعة ، ج21 ،ص490؛ بحار الانوار ، ج71 ؛ ص56)۔
ب: دوسری مشابہت
ایک اور مشابہت بہت خاص طور پر قابل غور ہے، خدا کی ذات حیّ و قیّوم ہے ابدی و سرمدی۔ نہ اس کی ذات فانی ہے نہ اس کی حکومت منقطع ہونے والی ہے۔ اس کے برعکس حیات انسانی چند روزہ ہے۔قیاس اس بات کا مقتضی تھا کہ جیسے ہی والدین کے حیات کا سلسلہ منقطع ہو اولاد کے سر سے ان کی اطاعت کا بار بھی اتر جائے ۔لیکن شریعت اسلام نے شاید یہ طے کر لیا تھا کہ ان کے ارباب مجاز ی یعنی والدین کو خدا کی ربوبیت کا کامل نمونہ بنا دے اور ان کے دنیا سے گذر جانے کے بعدبھی ان کے حقوق کی ذمہ داری اولاد پر باقی رہے۔یعنی جب تک اولاد زندہ رہے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتی رہے۔
امام محمد باقر ؑ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:
’’إِنَ الْعَبْدَ لَيَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِي عَنْهُمَا دَيْنَهُمَا وَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَى دَيْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارّاً‘‘۔
’’کبھی بندہ والدین کی زندگی میں ان کا مطیع و فرماں بردار رہتا ہے لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے نہ ان کے لئے استغفار کرتا ہے تو خدا اس کوعاق لکھ دیتا ہے۔ اور کبھی ان کی زندگی میں وہ ان کا نافرمان ہوتا ہے لیکن ان کے مر جانے پر ان کا قرض ادا کرتا ہے ان کے لئے استغفار کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کو مطیع و نیکوکار کار لکھ دیتا ہے‘‘ (بحارالانوار، ج71 ؛ ص59)۔
بنی سلمہ کے ایک شخص نے آنحضرتؐ سے پوچھا:
’’هل بقي من بر أبوىَّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟‘‘۔
’’ کیا میرے والدین کی وفات کے بعدبھی ان کا کوئی حق اطاعت باقی رہ گیا ہے جس سے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں‘‘؟
آنحضرتؐ نے فرمایا:
’’نعم الصلوة عليهما، و الاستغفار لهما، و إنفاذ عهد هما من بعد هما، و إكرام صديقهما․․․‘‘۔
’’ہاں! ان پر نماز پڑھنا، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا․․․‘‘( تفسير نور الثقلين ،ج3 ؛ ص151)۔
ج: تیسری مشابہت
اسی روایت سے ایک اور مشابہت کا پتہ چلتا ہے۔جس طرح اولیائے خدا کی تعظیم، حقوق خداوندی کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے اسی طرح والدین کے دوستوں کی تعظیم و تکریم بھی ان کے واجب الادا حقوق میں شامل ہے۔
۸: ماں کے حقوق کی عظمت و برتری
یہاں تک تو ماں اور باپ دونوں کے حقوق کا عمومی حیثیت سے تذکرہ تھا۔لیکن یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ اولاد کی پیدائش اور تربیت میں ماں جتنی زحمتیں ہنس ہنس کر برداشت کرلیتی ہیں عطوفت پدری ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسلام دین فطرت ہے اس نے کہیں بھی فطری تقاضوں سے تغافل نہیں برتا ہے ۔ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آیتوں میں خصوصیت سے صرف ماں کی زحمت کشی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
’’حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلىٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ‘‘۔
’’اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہہ کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کی دودھ بڑھائی کی‘‘(سورہ لقمان، آیت14)۔
’’حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً‘‘۔
’’اس کی ماں نے رنج ہی کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور رنج ہی میں اس کو جنا ۔اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت تیس مہینے ہوئے ‘‘ (سورہ احقاف، آیت15) ۔
حکیم بن حزام نے رسالتمآبؐ سے دریافت کیا :
’’يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟
اے اللہ کے رسولؐ !میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟
آپؐ نے جواب دیا:
أُمَّكَ
اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔
انہوں نے پوچھا:
ثُمَّ مَنْ؟
پھر وہی جواب ملا:
أُمَّكَ
(ماں کے ساتھ بھلائی کر)۔
انہوں نے پھر جرأت کی:
ثُمَّ مَنْ؟
اس کے بعد کون حسن سلوک کا مستحق ہے؟
پھر وہی جواب ملا:
أُمَّكَ
تیری ماں مستحق ہے۔
چوتھی مرتبہ پھر پوچھا:
ثُمَّ مَنْ؟
اب آنحضرتؐ نے فرمایا:
أَبَاكَ
اپنے باپ سے نیکی کے ساتھ پیش آ‘‘۔(الكافي، ج2؛ص159-160 و ج3؛ ص409؛ بحارالانوار، ج71، ص49)۔
اس روایت کی وجہ سے علماء نے یہ کہا ہے کہ ماں کا حق باپ کے حق سے تین گنا زیادہ ہے۔ آنحضرت ؐ نے مزید فرمایا ہے :
’’الجنّة تحت أقدام الامّهات‘‘(نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسولؐ)، ص434)۔
جسے میر انیس مرحوم نے ایک مرثیہ میں یوں نظم فرمایا ہے :
’’سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے‘‘
۹۔ ایک ضروری تنبیہ
اسلام نے والدین کے حقوق و اختیارات کو بہت وسیع کردیا ہے۔ لیکن یہ اختیارات اپنے ساتھ کچھ پابندیاں بھی لاتے ہیں۔ ماں باپ کو ذمہ دار سرپرست بنناہے نہ کہ مطلق العنان ڈکٹیڑ۔ اکثر کم ظرف افراد اپنے حقوق کا غلط استعمال کر کے خاندان و معاشرت کے لئے خطرہ بن جاتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہئے کہ ہرحق اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی لاتا ہے۔ اسی لئے شارع اسلام نے ان حقوق و اختیارات کے عطا کرنے کے ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی ہے کہ :
’’لعن اللہ الوالدین حملا اولاھما علیٰ عقوقھما‘‘
’’خدا ان والدین پر لعنت کرے جو اپنی اولاد کو اپنی نافرمانی پر مجبور کردیں‘‘(انوار الہدایہ)۔
اگر والدین خود اولاد کے حقوق کو نہ ادا کریں، ان کو صحیح تعلیم و تربیت سے ناآشنا رکھیں یا ان پر اتنا بوجھ لادنےکی کوشش کریں جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں یا ضرورت سے زیادہ تشدد و تندخوئی سے پیش آئیں تو درحقیقت وہ خود ہی اولاد کو بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں، نا فرمانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ اور ایسی صورت میں خاتم المرسلینؐ کی زبان سے نکلے ہوئے مذکورہ بالا الفاظ ان کے لئے طوق لعنت بن جائیں گے۔ خداوندعالم ہم سب کو یہ توفیق کرامت فرمائے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے گردن دوسروں کے حقوق سے گراں بار نہ ہو۔
۱۰۔ قرآن اور انجیل
ریونڈجی مارگولیوتھ(Rev.G.Margoliouth) نے یورنڈجے۔ایم۔ روڈول (Rev.G.M.Rodwell) کے انگریزی ترجمہ قرآن (The Koran) کے ’’تعارف‘‘ میں لکھا ہے:
’’قرآن جن اخلاقی تعلیمات پر حاوی ہے ان کے نقائص اس وقت بہت صاف طور سے سامنے آ جاتے ہیں ہیں جب ان کا تقابل اس بلند ترین اخلاقی میعار سے کیا جاتا ہے جس سے ہم آشنا ہیں (یعنی انجیل کے معیار سے)‘‘
(The Koran (Rev. G.M. Rodwell), Introduce Tion, Rev. G. Margoliouth)
ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے کہ قرآن اور قرآن کے لانے والے پیغمبرؐ نے والدین اور اولاد کے باہمی دینی اور اخلاقی حقوق و فرائض کے متعلق کیا بتایا اور سکھایا ہے۔ اب ذرایہ بھی دیکھتے چلیں کہ اس کے بارے میں انجیل کا ’’بلند ترین اخلاقی معیار‘‘ کیا ہے؟۔ انجیل متیٰ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں کہتی ہے:
’’جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ ہی رہا تھا تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا: کون ہے میری ماں اور کون ہیں میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا : ’’دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں‘‘(انجیل متی، باب12، آیت46-49)۔
سبحان اللہ! اپنے والدہ کے بارے میں گفتگو کرنے کا کتنا مہذب اندازاور دلنشین اخلاقی اسلوب ہے۔
ہم مسلمان جانتے ہیں حضرت عیسیؑ اپنی مقدس اور معصومہ ماں(علیہاالسلام) کے لئے یہ الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرسکتے تھے۔لیکن ہمارا یہ علم اور اعتقاد ’’انجیل‘‘ پر نہیں بلکہ قرآن پر مبنی ہے جس میں حضرت عیسیؑ کے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔
’’وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبّٰاراً شَقِيًّا‘‘۔
’’اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے تند خو اور بدبخت نہیں بنایا ہے‘‘(سورہ مریم، آیت32)۔
اب اہل نظر خودفیصلہ کر لیں کہ کون سی کتاب ’’بلند ترین اخلاقی معیار‘‘ پیش کرتی ہے۔
ریورنڈ ر و ڈول نے سورہ نسا٫ کی آیت 36:
’’وَ اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لاٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً‘‘۔
’’اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو ‘‘(سورہ نسا٫، آیت36)۔
کے ذیل میں حاشیہ لکھا ہے کہ:
’’مصریوں بلکہ عموما تمام عربوں میں نافرمان بچہ شاذ و نادر ہی سننے میں آتا ہے۔ بچوں کو جب تک حکم نہ دیا جائے وہ نہ تو باپ کے سامنے بیٹھتے ہیں نہ کھاتے ہیں، نہ تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ وہ اکثر کھانے کے وقت اور دوسرے مواقع پر اپنے باپ اور اس کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں ۔ کافی سن رسیدہ ہو جانے کے بعدبھی ان کے اس معمول میں فرق نہیں آتا‘‘(موجودہ مصر، لین، ج۱، ص۶۹۔ Lane, Modern Egypt))۔
ریورنڈ روڈول نے لین کے اس مشاہدہ کو اس آیت کا حاشیہ قرار دے کرصریحاً اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں میں والدین کا اس قدر ادب و لحاظ بہ راہ راست قرآنی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اب ریورنڈر مارگو لیوتھ سے اتنا کہنا پڑتا ہے کہ ؎
بازار مصر میں چل یوسف ؑ کا سامنا کر
کھوٹے کھرے کا پردہ کھل جائے گا چلن میں
(نوٹ: مابقیہ مطالب آئندہ شمارے میں شائع ہوں گے)